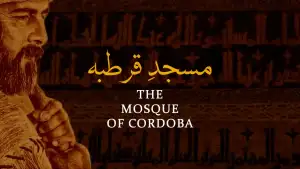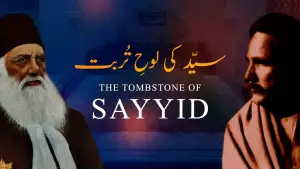نظم ”دردِ عشق“ از علامہ اقبال
فہرست
تعارف
علامہ اقبال کی نظم دردِ عشق پنجۂ فولاد لاہور میں 28 ستمبر 1903ء میں شائع ہوئی اور پھر العصر مارچ 1913ء کی اشاعت میں۔ یہ نظم 21 اشعار پر مشتمل تھی۔ بانگِ درا میں شامل کرتے وقت 8 منسوخ کیے گئے اور 13 شامل کر لیے گئے۔
اس نظم میں علامہ اقبال نے عشق سے براہِ راست خطاب کیا ہے اور اس کے ذریعے اس کی قدرت، اہمیت اور اصلیت کو واضح کیا ہے۔ یہ نظم اہم اس لیے ہے کیونکہ اس میں وہ ابتدائی خیالات ملتے ہیں جن پر آگے چل کر اقبالؔ نے اپنے فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ بانگِ درا میں عشق کا یہ تصور، جسے انہوں نے پیش کیا، بعد میں ”ارمغانِ حجاز“ میں ایک مضبوط اور تناوَر درخت بن گیا۔
اقبالؔ کے نزدیک عشق وہ پُرخلوص جذبۂ خدمت اور ایثار ہے جو انسان کو اپنے مقصد اور حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جذبہ چاہے قوم، ملک، دین یا انسانیت کی خدمت کے لیے ہو، دورِ قدیم میں اس کی مثالیں کثرت سے ملتی تھیں، لیکن دورِ حاضر میں یہ قدرے کم ہو چکا ہے۔ اقبالؔ اس نظم میں اسی عشقِ حقیقی کو بیدار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، جو زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگرچہ دورِ حاضر کے حالات اس کے لیے زیادہ موافق نہیں ہیں، نظم کا انداز نئے اور اثر انگیز طریقے سے اسی جذبے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
مزید یہ کہ اقبالؔ عقل اور عشق کو انسان کے کمال تک پہنچنے کے دو اہم ذرائع قرار دیتے ہیں۔ عقل کے ذریعے انسان استدلال اور فکر سے حقیقت کے قریب پہنچتا ہے، مگر عقل کی حدود ہیں: یہ محض مشاہدہ، قیاس اور سوچ کے ذریعے کام کرتی ہے اور انسان کو قطعی یقین یا مکمل تسکین نہیں دیتی۔ اس لیے عقل کا انجام اکثر حیرت اور سوال کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن عشق کی بدولت انسان ایک ہی قدم میں یقین کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبالؔ نے جابجا عقل پر عشق کی فوقیت ظاہر کی ہے، کیونکہ عشق انسان کو نہ صرف سوچنے والا بلکہ زندہ اور فعال جستجو کرنے والا بناتا ہے۔
عشق کے موضوع پر علامہ اقبال کی دِیگر نظمیں بانگِ درا 69: حُسن و عشق اور ضربِ کلیم 11: عِلم و عشق بھی ملاحظہ فرمائیں۔
نظم ”دردِ عشق“ کی تشریح
بند نمبر 1
اے دردِ عشق! ہے گُہرِ آب دار تُو
نامحرموں میں دیکھ نہ ہو آشکار تُو!

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| گُہرِ آب دار | چمکتا ہوا موتی |
| نامحرم | ناآشنا، بیگانہ |
| آشکار | ظاہر |
تشریح:
اے دردِ عشق! تُو ایک چمکیلا موتی ہے جس کی آب و تاب کا اندازہ ہر آنکھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے تُو اُن لوگوں پر ظاہر نہ ہو جو تیری قدر و قیمت سے آگاہ نہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک عشق ایک عام کیفیت یا محض جذباتی واردات نہیں بلکہ وہ گوہرِ نایاب ہے جو انسان کو حقیقتِ مطلق تک پہنچاتا ہے۔ یہی عشق انسان کو جُراتِ رندانہ، تسخیرِ کائنات اور بندگیِ ربانی کی قوت بخشتا ہے۔ اقبالؔ عشق کو ’’گوہرِ آب دار‘‘ کہہ کر اُس کی بے پناہ قیمتی حیثیت کو اُجاگر کر رہے ہیں۔
یہاں اقبالؔ ایک اہم نُکتہ اٹھاتے ہیں کہ عشق کی حقیقت صرف اہلِ دل کے لیے ہے۔ جو لوگ محض مادیت (Materialism) کے اسیر ہیں، جو عقلِ جزوی پر قانع ہو کر عشق کی روشنی سے محروم ہیں، اُن کے سامنے عشق کے راز کھول دینا بیکار ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے عشق کا بیان کرنا گویا اندھے کی آنکھ میں سرمہ ڈالنے کے مترادف ہے۔
اقبالؔ کے ہاں یہ تصور بھی بہت نمایاں ہے کہ بعض حقائق ہر کسی پر ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ اسرارِ خودی اور دردِ عشق کا بیان صرف اُن دلوں کے لیے ہے جو ظرف رکھتے ہیں۔ اگر ان حقائق کو نااہلوں پر ظاہر کیا جائے تو وہ ان کا مذاق اڑائیں گے یا ان کی بے قدری کریں گے۔
پنہاں تہِ نقاب تری جلوہ گاہ ہے
ظاہر پرست محفلِ نَو کی نگاہ ہے

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| پِنہاں | چھُپا ہوا |
| تہِ نقاب | پردے کے نیچے |
| جلوہ گاہ | ظاہر ہونے کی جگہ |
| ظاہر پرست | ظاہری چیزوں کو پسند کرنے والی |
| محفلِ نو | نیا زمانہ، تازہ مجلس |
تشریح:
تیرے جلوے کی جگہ پردے میں چھُپی ہوئی ہے، جبکہ موجودہ دور کے لوگ صرف ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں، اُن کی نظر باطن تک پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ یعنی جن دلوں میں انسانیت، قوم یا دین کی خدمت کا جذبہ سچا اور بے لوث طور پر جاگتا ہے، وہ اپنی خدمت کی نمائش نہیں کرتے۔ وہ خلوص کے ساتھ اپنے فرائض چُپکے چُپکے ادا کرتے ہیں۔ یہی دراصل عشق کی سچی علامت ہے۔ لیکن آج کا زمانہ ایسے خلوص کی قدر نہیں کرتا۔ یہاں وہی لوگ مقبول ہیں جو ہر وقت اپنی کامیابیوں کے ڈھول بجاتے اور اپنے کارناموں کے قصے سناتے رہتے ہیں۔ عشق کی کیفیت تو اُس حسین چہرے کی مانند ہے جو نقاب میں چھُپا ہو، لیکن پھر بھی اپنی روشنی اور دِلکشی سے پہچانا جاتا ہے۔
آئی نئی ہوا چمنِ ہست و بود میں
اے دردِ عشق! اب نہیں لذّت نمود میں

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| نئی ہوا | مراد نئے طور طریقے / خیالات |
| چمنِ ہست و بُود | مراد کائنات، دُنیا |
| نمود | ظاہر ہونا |
تشریح:
زندگی کے منظرنامے میں ایک نیا دور آیا ہے اور پرانے انداز و اقدار بدل چکے ہیں۔ خلوص اور نیک نیتی کی وہ قدر باقی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اے دردِ عشق! اب دنیا کے سامنے ظاہر ہونے میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ ایک وقت تھا جب تجھے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اب زمانے کا زاویۂ نگاہ بدل گیا ہے اور نئے خیالات و نظریات کی موجودگی میں تیرے اظہار کی تاثیر گھٹ گئی ہے۔
اس دور کے لوگ مادہ پرست اور مغرب زدہ ہو چکے ہیں۔ ان کے دلوں میں روحانیت کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے اور نگاہیں صرف ظاہر پر مرکوز ہیں۔ لہٰذا عاشقانِ حق کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گوشۂ تنہائی اختیار کریں اور خودنمائی، تشہیر و شہرت سے گریز کریں، کیونکہ یہ رویے سچے عشق کے مزاج اور اصول کے سراسر خلاف ہیں۔
ہاں، خود نمائیوں کی تجھے جُستجو نہ ہو
منّت پذیر نالۂ بُلبل کا تُو نہ ہو!

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| خود نمائی | خود کو ظاہر کرنا |
| جستجو | ڈھونڈنے کا عمل، تلاش، کھوج، کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش |
| منت پذیر | احسان اُٹھانے والا |
| نالۂ بُلبُل | بُلبُل کا رونا |
تشریح:
اے عشق! تُو ہمیشہ دِکھاوے اور نمود و نمائش سے بے پروا رہا ہے، اور یہی تیری اصل شان ہے۔ اب بھی تجھے خودنمائی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنی خدمات اور اپنے جوش و جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے تجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ بلبل جب پھول کے فراق میں نالہ و فریاد کرتی ہے تو یہ اس کے دردِ عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ اخلاص اور سچائی کی قدر و قیمت باقی نہیں رہی، اس طرح کا اظہار بھی بے سود ہے۔ اس لیے تجھے بلبل کی آہ و فغاں کا سہارا لینے یا اس کا احسان اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سچے عشق کی عظمت یہی ہے کہ وہ اپنے اندر کی تپش اور کیفیت کو سنبھال کر رکھے، نہ کہ دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر اپنی سچائی ثابت کرے۔
خالی شرابِ عشق سے لالے کا جام ہو
پانی کی بوند گریۂ شبنم کا نام ہو

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| لالہ | ایک نہایت سُرخ پھول جس کے درمیان سیاہ داغ ہوتا ہے ، گُلِ لالہ |
| جام | وہ پیالہ جس میں شراب ڈالتے ہیں |
| گِریۂ شبنم | شبنم کا رونا / آنسو بہانا |
تشریح:
اے دردِ عشق! موجودہ حالات میں تیرا مقام یہ ہے کہ تُو اپنی تجلیات کو پسِ پردہ رکھے۔ اگرچہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لالے کے داغ میں بھی محبت کا پیغام نہ رہے اور شبنم کے قطرے بھی بس عام پانی دکھائی دیں۔ گُلِ لالہ کو شاعروں نے ہمیشہ عشق کی علامت سمجھا ہے۔ اس پھول کی شکل پیالے (جام) جیسی ہے اور اس کے اندر موجود داغ کو ”عشق کا داغ“ کہا جاتا ہے۔ اگر دردِ عشق زمانے کی ناموافقت کے باعث پسِ پردہ چلا جائے تو لالے کا پیالہ عشق کی شراب سے خالی ہو جائے گا اور شبنم کے قطرے بھی محض پانی کی بوندیں رہ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں کے آنسو یا شبنم کے قطرے اُس وقت بامعنی ہوتے ہیں جب دل کی تڑپ اور عشق کی حرارت سے جُڑے ہوں، ورنہ وہ محض پانی ہیں۔ اسی نسبت سے شبنم کو عشق کی بدولت ”گریہ“ کہا گیا ہے۔ گویا لالہ، شبنم اور آنسو، سب کی معنویّت عشق سے ہے۔ اگر عشق دب جائے یا اپنی تجلیات ظاہر نہ کرے تو یہ سب نشانیاں محض ظاہری صورتیں بن کر رہ جاتی ہیں، جن میں نہ روح باقی رہتی ہے نہ تاثیر۔
پنہاں دُرونِ سینہ کہیں راز ہو ترا
اشکِ جگر گداز نہ غمّاز ہو ترا

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| پنہاں | چھُپا ہوا |
| درُونِ سینہ | سینہ کے اندر / دِل میں چھُپا ہوا |
| اشکِ جِگر گُداز | جِگر کو پِگھلا دینے والا آنسو |
| غمّاز | چُغلی کھانے والا، نشاندہی کرنے والا |
تشریح:
اقبالؔ کہتے ہیں کہ اے دردِ عشق! تیرا مقام اصل میں انسان کا دل ہے، اس لیے تیرا بھید سینے کے کسی کونے میں چھُپا رہنا چاہیے۔ اگر تُو ظاہر ہو جائے تو زمانے کی ظاہر پرست آنکھیں اسے محض ایک کمزوری یا جذباتی کیفیت سمجھیں گی، اور وہ اس کی اصل عظمت کو نہ جان پائیں گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جگر کے گھُلنے سے جو آنسو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی باہر نہ آئیں، ورنہ وہ تیرے راز کو فاش کر دیں گے۔
گویا زبانِ شاعرِ رنگیں بیاں نہ ہو
آوازِ نَے میں شکوۂ فُرقت نہاں نہ ہو

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| گویا | بولنے والا / والی |
| رنگیں بیاں | اچھے شعر کہنے والا |
| نَے | بانسُری |
| فُرقت | جُدائی |
تشریح:
اقبالؔ یہاں عشق کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کیفیت کو ظاہر نہ کرے۔ اگر شاعرِ رنگیں بیاں یعنی الفاظ کا جادوگر تیری داستان بیان کرے گا تو دورِ حاضر کے لوگ اسے محض ایک فنکارانہ کمال یا زبان و بیان کی رنگینی سمجھیں گے۔ اس میں چھُپی ہوئی باطنی آگ اور روحانی تڑپ ان کی سمجھ سے بالاتر ہوگی۔ اسی طرح اگر عشق اپنی کیفیت کو بانسری کی آواز میں ظاہر کرے، جیسا کہ مولانا رومؒ نے بانسُری کی فریاد کو جُدائی کا استعارہ بنایا تھا، تو آج کا ظاہر پرست انسان اسے محض موسیقی اور سُر سمجھ کر لطف اندوز ہوگا، اور اس میں پوشیدہ روحانی صداقت کو نظر انداز کر دے گا۔ اس لیے موجودہ دور کا تقاضا یہی ہے کہ عشق کے معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔
اس شعر میں علامہ اقبال دورِ حاضر کے فکری زوال اور مغرب زدگی پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ اُن کے نزدیک جدید دنیا نے ہر چیز کو ظاہر، نمائش اور فن کے پیرائے میں محدود کر دیا ہے۔ عشق جو دراصل باطن کی آگ ہے، اور انسان کو خدا سے جوڑنے والی قوت ہے، اگر اس کو اس دور کے ظاہر پرست ماحول میں پیش کیا جائے تو وہ محض تفریح یا جذباتی شاعری بن کر رہ جائے گا۔ مغرب زدہ ذہن روحانیت کو سمجھنے کے بجائے آرٹ اور فن کی تکنیک پر داد دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبالؔ عشق کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اظہار کو موسیقی، شاعری یا ظاہر کی سطح پر نہ لائے بلکہ اسے خاموشی اور باطن میں چھپا کر رکھے، تاکہ اس کی اصل تاثیر محفوظ رہے۔
یہ دَور نُکتہ چیں ہے، کہیں چھُپ کے بیٹھ رہ
جس دل میں تُو مکیں ہے، وہیں چھپ کے بیٹھ رہ

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| نُکتہ چیں | نقص نکالنے والا |
| مکیں | رہنے والا، مقیم |
تشریح:
اے عشق! آج کا زمانہ نکتہ چینی اور عیب جوئی کا زمانہ ہے۔ یہ لوگ ظاہری علامات کو دیکھتے ہیں مگر ان کے باطن تک رسائی نہیں رکھتے۔ اگر تُو اپنی حقیقت کو آنسو، گریہ، شبنم، بلبل کی فریاد یا شاعر کی زبان کے ذریعے ظاہر کرے گا تو یہ سب محض ایک ”فن“ یا ”ادب کا انداز“سمجھا جائے گا، نہ کہ تیری اصلی روح۔ اس لیے بہتر ہے کہ تُو خاموش رہے، اپنے اصل مقام یعنی دل کے اندر چھُپ کر بیٹھا رہے۔
یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عشق کا اظہار مادی علامات جیسے آنسو یا فریاد سے نہ ہو تو دوسروں کو کیسے معلوم ہوگا کہ کسی دل میں عشق ہے؟ جواب یہ ہے کہ عشق اپنی سچائی کے لیے دوسروں کے اعتراف کا محتاج نہیں۔ عشق کا اصل مقام باطن ہے، اور اس کی اصل علامت ظاہری فریاد نہیں بلکہ باطنی انقلاب ہے۔ جب دل عشق سے سرشار ہوتا ہے تو وہ خود عاشق کی زندگی، کردار، استقلال اور عمل میں جھلکتا ہے۔ یہ تاثیر اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ بغیر آنسو یا فریاد کے بھی لوگ اس کے اثر کو محسوس کرتے ہیں۔
تنقیدی پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ شعر اُس دور کی عکاسی کرتا ہے جب مغرب میں ”فن برائے فن (Art for Art’s Sake)“ کا تصور زور پکڑ رہا تھا اور ادب و فن محض جمالیاتی کھیل سمجھے جا رہے تھے۔ اسی طرح برِصغیر کا ماحول بھی مادیت، ظاہربینی اور سطحی ذوق کا شکار ہو چکا تھا۔ ایسے دور میں اگر عشق کا اظہار محفلوں میں آنسو یا شعروں کی صورت میں ہوتا تو لوگ اسے محض ایک جذباتی مشغلہ یا ادبی ”فنکاری“ سمجھتے۔ اقبالؔ چاہتے ہیں کہ عشق اپنی اصل طاقت یعنی ”کردار سازی“ اور ”انسانی زندگی میں انقلاب “ کی صورت میں سامنے آئے، نہ کہ محض شاعرانہ ادا یا فن کی لذت بن کر رہ جائے۔
یوں اس شعر کا لُبِ لباب یہ ہے کہ عشق اپنی اصل حقیقت میں ایک باطنی قوت ہے، جو خاموشی کے باوجود اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ اسے دنیاوی نمائش یا مادی علامتوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی اصل قوت خود عاشق کی زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتی ہے۔
بند نمبر 2
غافل ہے تجھ سے حیرتِ علم آفریدہ دیکھ!
جویا نہیں تری نگہِ نا رسیدہ دیکھ

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| حیرتِ علم آفریدہ | علم کی پیدا کی ہوئی حیرت / حیرانی |
| جویا | تلاش کرنے والی |
| نگہِ نارسیدہ | وہ آنکھ جو حقیقت تک نہ پہنچے، وہ نظر جو حقیقت بیں نہ ہو |
تشریح:
یہاں اقبال ”دردِ عشق“ کو یاد دلاتے ہیں کہ سائنس و علم کی نئی نئی فتوحات اور انکشافات نے انسان کو حیرت میں تو ڈال دیا ہے، مگر اِن علوم کے حامل افراد عشق کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اُن کی نظر بلند تو ہے مگر حقیقت کی گہرائی تک نہیں پہنچتی، اس لیے وہ عشق کو ڈھونڈنے کے بھی اہل نہیں۔
اگر آج کے دور پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے خلاء کی تسخیر کر لی ہے، چاند پر جا چکا ہے، مریخ پر مشنز بھیج رہا ہے، اور بلیک ہول کی تصویریں تک کھینچ چُکا ہے، لیکن اقبالؔ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ”دردِ عشق“ کے بغیر ہے۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو سہولتیں دیں، کائنات کے راز کھولے، لیکن انسان کے اندر کے خلا، تنہائی، اور روحانی بےچینی کو ختم نہ کر سکی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا میں ڈپریشن، وجودی بحران، اور مقصدِ زندگی کو لے کر سوالات مزید بڑھ گئے ہیں۔
اسی طرح مصنوعی ذہانت (Artificial Intelligence) نے انسانی سوچ، تحریر اور فیصلہ سازی تک کی مشابہت پیدا کر دی ہے۔ انسان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جو چند سیکنڈ میں اربوں ڈیٹا پوائنٹس پروسیس کر کے حیران کن نتائج دے دیتی ہے۔ یہ سب واقعی ”حیرتِ علم آفریدہ“ ہے، یعنی ایک ایسا علم جو مسلسل تعجب اور ششدر کر دینے والے انکشافات کرتا ہے۔
یہی اقبالؔ کا مُدعا ہے: صرف ”علم“ انسان کو سکون یا حقیقت نہیں دے سکتا، جب تک کہ وہ “عشق” کی روشنی سے جُڑ نہ جائے۔ عشق ہی وہ قوت ہے جو علم کو منزل کی طرف رہنمائی دیتا ہے، ورنہ علم محض حیرت اور اُلجھن کا سامان بن کر رہ جاتا ہے۔
رہنے دے جُستجو میں خیالِ بلند کو
حیرت میں چھوڑ دیدۂ حکمت پسند کو

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| جُستجو | ڈھونڈنے کا عمل، تلاش، کھوج، کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش |
| دیدۂ حکمت پسند | دانائی کی باتیں پسند کرنے والی آنکھ |
تشریح:
واضح ہو کہ فلسفہ، سائنس اور حکمت کے مُدعی لوگ حقیقتِ مطلقہ تک عشق کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اُن کی آنکھ (دیدۂ حکمت پسند) اگرچہ کائنات کا مشاہدہ کرتی ہے اور فکر و نظر کے ذریعے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چونکہ عشق اس میں شامل نہیں، اس لیے اُن کی جستجو محض ”خیالِ بلند“ رہتی ہے، یعنی محض ذہنی کھیل اور تصورات کی دنیا۔ عشق کے بغیر ان کی آنکھ حیرت میں ہی بھٹکتی رہتی ہے اور حقیقت کے سُراغ تک نہیں پہنچتی۔
؎ انکشافِ رازِ ہستی عقل کی حد میں نہیں
فلسفی یاں کیا کرے اور سارا عالم کیا کرے
اقبالؔ گویا یہ پیغام دیتے ہیں کہ: اے عشق! تُو اپنی اصل حقیقت کو زمانے کے ان فلسفیوں اور سائنس دانوں پر ظاہر نہ کر۔ چونکہ یہ تجھ سے بے تعلق ہیں، انہیں اپنی وادیٔ حیرت میں سرگرداں رہنے دے۔ یہ لوگ علم کی جستجو میں اپنی عمریں صرف کر دیں گے مگر چونکہ ان کے پاس ”عشق“ کی کلید نہیں، اس لیے رازِ حقیقت کبھی اِن پر نہیں کھلے گا۔ حقیقت کی منزل تک پہنچنے کے لیے ”عشق“ ہی اصل رہنما ہے، نہ کہ محض حکمت و فلسفہ۔
اگر آج کے دور میں اس کا تناظر دیکھیں تو سائنس نے کائنات کے نہایت دقیق اسرار کو کھولا ہے، مگر انسان کی روحانی بےچینی بڑھ گئی ہے۔ فلسفۂ وجود (existentialism)، الحاد (atheism) اور مادیّت (materialism) اسی ”دیدۂ حکمت پسند“ کی حیرانی کی علامات ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اپنے علم پر ناز ہے، وہ حقیقت کو محض عقل سے پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چونکہ عشق کی روشنی سے بے بہرہ ہیں، اس لیے نتیجہ ہمیشہ شک، حیرت اور عدمِ اطمینان کی صورت میں نکلتا ہے۔
جس کی بہار تُو ہو یہ ایسا چمن نہیں
قابل تری نمود کے یہ انجمن نہیں

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| چمن | باغ |
| نمود | ظاہر ہونا |
| انجمن | محفل |
تشریح:
اے دردِ عشق! موجودہ دور کا ماحول ایسا نہیں رہا جو تیری بہار کو قبول کر سکے۔ جس باغ (یعنی جس معاشرے یا تہذیب) میں عشق کھِلنا چاہے، وہاں کے لوگ اتنے بے ذوق اور ظاہر پرست ہو گئے ہیں کہ اس کی لطافت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ گویا یہ چمن، جس کی آبادی مادی خواہشات، نمود و نمائش اور خود غرضی پر قائم ہے، عشق کے کھلنے اور پروان چڑھنے کے قابل نہیں۔
اس شعر میں اقبالؔ نے دورِ حاضر کے معاشرتی اور فکری زوال پر کڑی تنقید کی ہے۔ یورپ کے زیرِ اثر پیدا ہونے والا ماحول صرف عقل، سائنس اور مادیّت پر فخر کرتا ہے۔ یہاں دل کی گہرائیوں، روحانی تجربے یا عشقِ حقیقی کی کوئی قدر باقی نہیں رہی۔ یہ انجمن، جو بظاہر ترقی یافتہ نظر آتی ہے، دراصل عشق کے اظہار کے لیے ناسازگار ہے۔ عشق اگر اس میں ظاہر ہو بھی تو لوگ اسے محض شاعرانہ خیال یا جذباتی کمزوری سمجھیں گے، اس کے اندر چھپی ہوئی روحانی صداقت کو نہیں دیکھیں گے۔ اس پس منظر میں یہ شعر دردِ عشق کو خاموشی اور پردہ اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ یعنی اے عشق! تُو اپنے اظہار سے اجتناب کر، کیونکہ یہ دور تیرا استقبال کرنے والا نہیں بلکہ تجھ پر ہنسنے اور نکتہ چینی کرنے والا ہے۔ تیرے جلوے کی جگہ ایسا معاشرہ ہے جہاں دل زندہ ہوں، جہاں لوگ باطن کی روشنی کو سمجھنے والے ہوں۔ لیکن یہ محفلِ نو، جو محض ظاہر پرستی، مادہ پرستی اور عقل پرستی پر قائم ہے، تیرے لائق نہیں۔
یہ انجمن ہے کُشتۂ نظّارۂ مجاز
مقصد تری نگاہ کا خلوت سرائے راز

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| کشتہ | مِٹا ہوا، مرا ہوا |
| نظارۂ مجاز | ظاہری نظارہ |
| خلوت سرائے راز | راز کا خلوت کدہ، راز کا مکان |
تشریح:
علامہ اس شعر میں موجودہ زمانے کی فکری کمزوری اور عشق کی اصل حقیقت کے درمیان فرق کو واضح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی انجمن (یعنی جدید تہذیب، محفلِ نو یا معاشرہ) محض “مجاز“ کے نظاروں کی اسیر ہے۔ یہ دنیا صرف ظاہر، مادی خوشنمائی، سطحی جمال اور آنکھوں کو بھانے والے مناظر پر مر مِٹتی ہے۔ یہاں ہر شخص کا شوق اور ذوق اسی فانی، وقتی اور محسوس ہونے والی چیزوں تک محدود ہے۔ اس کے برعکس، دردِ عشق کی اصل منزل ”خلوت سرائے راز“ ہے یعنی وہ مقام جہاں حقیقت کے اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں۔ عشق کا نگاہی مقصد یہ ہے کہ وہ باطن میں جھانکے، پردوں کو چاک کرے اور حقیقت کے راز کو پائے۔ یہ وہ جہاں ہے جہاں صرف ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی بینائی اور روح کی بصیرت سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔
یوں یہ شعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ عشق اور زمانہ ایک دوسرے کے ساتھ غیر ہم آہنگ ہو چکے ہیں۔ آج کی انجمن عشق کی گہرائی کو قبول کرنے یا سمجھنے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ صرف مجاز کی طلب گار ہے۔ اس کے مقابلے میں عشق کا سفر ہی حقیقت کی تلاش ہے۔
یہاں اقبالؔ کا اشارہ واضح طور پر اس دور کی مادہ پرست تہذیب کی طرف ہے جو روحانی حقائق سے بیگانہ ہے۔ جدید انسان کی محفلیں موسیقی، آرٹ، شاعری اور دیگر فنون کو صرف تفریح اور لذتِ طبع کی سطح پر دیکھتی ہیں، مگر ان میں چھپی حقیقت کو نہیں پہچان پاتیں۔ اسی لیے عشق کی نگاہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ان سطحی نظاروں کے بیچ خود کو ظاہر نہ کرے بلکہ اپنی راہ حقیقت اور راز کی خلوت تک رکھے۔
ہر دل مئے خیال کی مستی سے چُور ہے
کچھ اور آجکل کے کلیموں کا طُور ہے

حلِ لغات:
| الفاظ | معنی |
|---|---|
| مئے خیال | خیالی شراب |
| چُور | سرمست، بدمست، نشے کی حالت میں |
| کلیم | کلیم اللہ (اللہ تعالی سے کلام کرنے والا): حضرت موسیؑ کا لقب |
| طُور | کوہِ طُور (Mount Sinai): وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیؑ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے |
تشریح:
آج کے دِل عشق کے سوز اور درد سے معمور نہیں، بلکہ محض خیالات، فلسفے اور نظریات کی مستی میں مدہوش ہیں۔ ”مئے خیال“ سے مراد وہ خشک عقلی اور فلسفیانہ مباحث ہیں جنہیں لوگ روحانی سرور اور باطنی بصیرت کا نعم البدل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب محض ذہنی کھیل ہیں، جن میں کوئی حقیقی سوز یا روحانی تاثیر نہیں۔ اسی طرح ”کلیموں کا طُور“ حضرت موسیؑ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جنہیں کوہِ طور پر جلوۂ حق کی تجلی نصیب ہوئی تھی۔ وہ ”طُور“ حقیقت کا مرکز تھا، جہاں بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوا۔ لیکن آج کے زمانے کے کلیم، جو حقیقت کے متلاشی بنے پھرتے ہیں، ان کا ”طُور“ کچھ اور ہے، یعنی وہ دنیاوی اغراض، مادی مفادات، یا محض سائنسی و فلسفیانہ منطق کو ہی اپنا کوہِ طور سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کا جلوہ عقل کی محدود روشنی یا مشاہدہ و تجربہ کے آلات سے دیکھا جا سکتا ہے۔
اقبالؔ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عشق کے بغیر کوئی بھی نگاہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ آج کے لوگوں نے عشق کو پسِ پُشت ڈال دیا ہے اور صرف عقل و فلسفے کے زور پر حقیقت کو پانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ محض سراب کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ہمیشہ حیرت و بھٹکاؤ میں مبتلا رہتے ہیں۔
تبصرہ
سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عقل اور فلسفہ کیا کرتے ہیں۔ عقل ہمیں دنیا کے بارے میں سوچنے، حساب لگانے، نظام بنانے اور مظاہرِ کائنات کو سمجھنے کی طاقت دیتی ہے۔ فلسفہ بھی انہی چیزوں کو اصولی اور منطقی انداز میں پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقبالؔ عقل اور فلسفہ کی اس صلاحیت کو رد نہیں کرتے، بلکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ لیکن اِن کی حد ہے: یہ صرف ظاہری دنیا تک رہنمائی کر سکتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ عقل کافی کیوں نہیں ہے؟ اقبالؔ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقل صرف وہ دیکھتی ہے جو آنکھ کے سامنے ہو یا جو منطقی استدلال سے اخذ کیا جا سکے۔ لیکن حقیقتِ کائنات، انسان کی اصل منزل اور زندگی کا مقصد صرف مشاہدے یا استدلال سے نہیں کھُلتا۔ عقل سوال پوچھتی ہے کہ ”کائنات کیسے بنی؟“ لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ ”کائنات کیوں بنی؟“۔ عقل جسم کے بارے میں سمجھا دیتی ہے مگر روح کی گہرائی کو نہیں چھُو سکتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل حیران ہو جاتی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے اُسے ایک اور قوت کی ضرورت ہے، اور وہ قوت عشق ہے۔
اقبالؔ کے نزدیک عشق محض ایک وجدانی کیفیت یا جذباتی وابستگی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باطنی روشنی اور الہی قوت ہے جو انسان کو حقیقتِ مطلق یعنی اللہ تک پہنچاتی ہے۔ عشق اندھا دھند جذبات کا نام نہیں، بلکہ اس کی پرورش وحیِ الہی کے زیرِ سایہ ہوتی ہے۔ وحی حقیقت کا علم عطا کرتی ہے، اور عشق اس علم کو دل و جان سے قبول کر کے عملی زندگی میں ڈھالنے کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ عقل کا سرمایہ ’’سوال‘‘ ہے، وحی کا سرمایہ ’’جواب‘‘ ہے، اور عشق اس جواب کو اپنی ہستی کا حصہ بنا لینے کا نام ہے۔
یقیناً دُنیا کے مختلف مذاہب میں عشق یا اس سے ملتے جُلتے تصورات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً بدھ مت میں ’’کرونا‘‘ (رحمت و ہمدردی)، ہندو فلسفے میں ’’بھکتی‘‘، عیسائیت میں ’’محبت‘‘ اور صوفی روایت میں ’’عشق‘‘۔ یہ سب انسانی جستجو کے مظاہر ہیں اور انسان کی فطرت میں رکھی گئی ’’چنگاری‘‘ کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اقبالؔ کے نزدیک یہ سب جُزوی ہیں۔ کامل اور حتمی عشق وہ ہے جو وحیِ محمدی ﷺ کے زیرِ اثر پروان چڑھتا ہے۔ یہی وہ سرچشمہ ہے جو عشق کو انسانی جذبات سے بلند کر کے الٰہی شعور سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا عشق اس لیے مختلف اور برتر ہے کہ وہ براہِ راست نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس سے جُڑا ہے جو وحی کے کامل مظہر ہیں۔
اقبالؔ کی تنقید یہ ہے کہ جدید دور کے انسان نے عقل کو تو اپنا سہارا بنایا مگر عشق کو بھُلا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم اور سائنس تو بڑھ گئی، مگر زندگی کے بڑے سوالوں کے جواب نہ مل سکے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا لیکن اپنے دل کے خلا کو پُر نہ کر سکا۔ اس نے ایٹم کو توڑ دیا لیکن اپنی روح کے اندھیروں کو نہ توڑ سکا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل کی ساری طاقتیں ناکافی ثابت ہوتی ہیں۔ اگر عقل ہی پر اکتفا کیا جائے تو انسان کے پاس معلومات تو ہوں گی مگر مقصد نہیں۔ لیکن جب عقل کے ساتھ عشق شامل ہو جائے تو پھر علم بھی روشنی بن جاتا ہے، فکر بھی عمل سے جُڑ جاتی ہے اور زندگی بھی ایک اعلی نصب العین کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ یہی اقبالؔ کا اصل پیغام ہے کہ عشق کے بغیر عقل ادھوری ہے اور وحی کے زیرِ سایہ پروان چڑھنے والا عشق ہی انسان کو حقیقتِ مطلق یعنی خدا سے ملا کر اس کی زندگی کو بامعنی بناتا ہے۔
’عشق ناپید و خرد میگزدش صُورتِ مار‘
عقل کو تابعِ فرمانِ نظر کر نہ سکا
ڈھُونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دُنیا میں سفر کر نہ سکا
اپنی حِکمت کے خم و پیچ میں اُلجھا ایسا
آج تک فیصلۂ نفع و ضرر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شُعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شبِ تاریک سحر کر نہ سکا!
(ضربِ کلیم 72: زمانۂ حاضر کا انسان)
حوالہ جات
- شرح بانگِ درا از پروفیسر یوسف سلیم چشتی
- شرح بانگِ درا از ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی
- شرح بانگِ درا ا ڈاکٹر شفیق احمد
- شرح بانگِ درا از اسرار زیدی
- شرح بانگِ درا از پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی
- مطالبِ بانگِ درا از مولانا غلام رسول مہر
- آوازِ اقبال – بانگِ درا مع مطالب از نریش کمار شادؔ